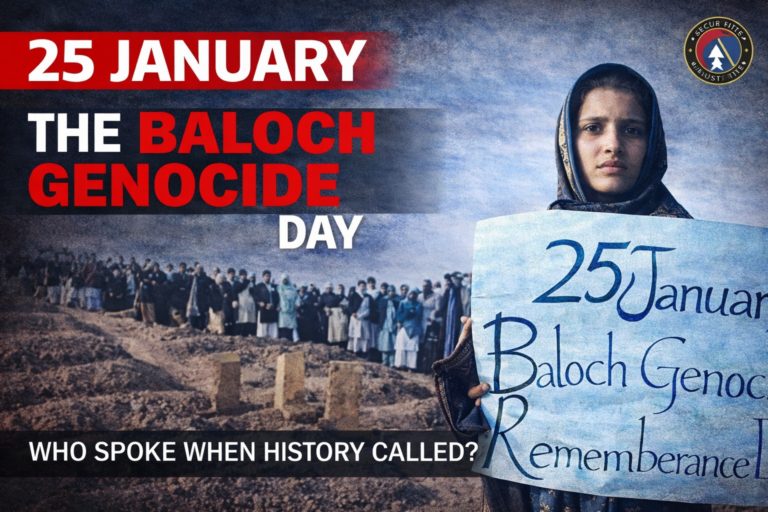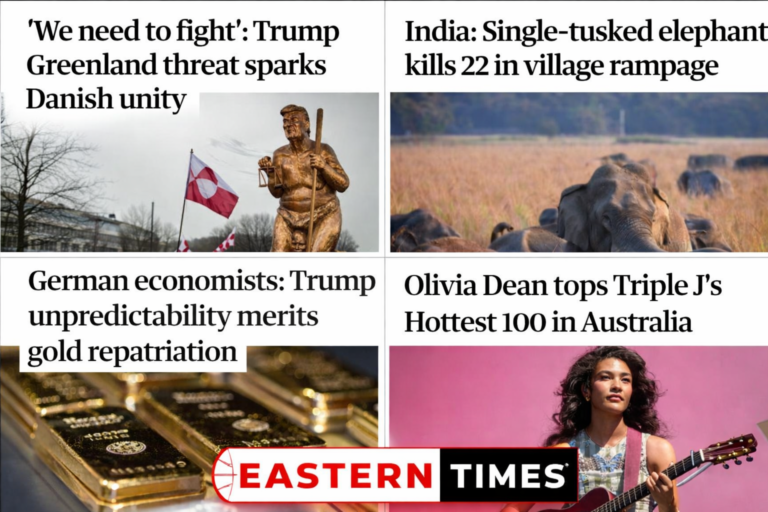روحانی تسلسل یا تاریخی جدلیات؟ پنجابی ترقی پسندی کا محاسبہ
یہ مضمون کسی تازہ خیال کی پیداوار نہیں، بلکہ وقت کی تہوں میں دبے ہوئے ایک فکری تجربے کی بازیافت ہے۔ پاکستانی پنجابی ادبی بورڈ لاہور کے چیئرمین آصف خان کا نوّے کی دہائی میں لکھا ہوا مضمون “الف اللہ”—جو اس عہد میں محض ایک ادبی تحریر نہیں بلکہ ایک فکری علامت تھا—آج اچانک میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں اپنے پرانے کاغذات کی جانچ پڑتال کر رہا تھا کہ ایک زرد ہوتی ہوئی فوٹو اسٹیٹ نقل ہاتھ لگ گئی؛ اس کے ساتھ ہی ایک اسٹڈی سرکل میں دی گئی میری لیڈ آف کے ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹس بھی نکل آئے۔ یوں لگا جیسے کاغذ نہیں، وقت کھل گیا ہو، اور یادداشت کی کسی بند تہہ میں دفن ایک پورا زمانہ سانس لینے لگا ہو۔
مجھے صاف یاد ہے کہ وہ دن کس قدر جوش اور فکری بے قراری سے بھرے ہوئے تھے۔ ہم نے لاہور میں ایک اسٹڈی سرکل شروع کیا تھا جس میں شہر کے مختلف تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے درجن بھر طلبہ و طالبات شریک ہوتے تھے۔ یہ کوئی رسمی مطالعہ نہیں تھا، بلکہ ایک فکری تجربہ گاہ تھی جہاں ہم یہ جانچنے کی جسارت کر رہے تھے کہ رِگ وید سے لے کر صوفیانہ متون تک—یعنی سپت سندھو کے قبائلی سماج سے جاگیرداری سماج تک کے وہ بنیادی مذہبی، صوفیانہ اور فکری متون جو پنجاب میں صوفیوں، سادھوؤں، سنتوں، گروؤں اور براہمنوں نے تخلیق کیے—انہیں تاریخ کے مادی جدلیاتی طریقۂ تحقیق کی روشنی میں کیسے پڑھا اور پرکھا جا سکتا ہے۔ یہ دراصل پنجابی قوم پرستانہ تاریخ کی اُس روایت کا تنقیدی مطالعہ تھا جو روحانیت، وحدت اور تقدیس کے پردے میں سماجی و طبقاتی تضادات کو منجمد کر دیتی ہے۔
ان دنوں ہم نے—میں اور میرے ایک قریبی دوست نے—لاہور میں موجود باحیات ترقی پسند اور مارکسسٹ دانشوروں سے ملاقاتیں بھی کیں۔ ہماری امید یہ تھی کہ شاید صفدر میر، ایرک سپرین جیسے معتبر نام اس موضوع پر کسی اسٹڈی سرکل نصاب کی تشکیل میں ہماری رہنمائی کر سکیں گے۔ مگر نتائج مایوس کن نکلے۔ یا تو یہ سوال ان کے فکری ایجنڈے سے باہر تھا، یا پھر اس وقت کی ترقی پسند روایت خود ایسے سوالات سے کتراتی تھی جو مذہب، تصوف اور قوم پرستانہ ثقافت کو مادّی جدلیاتی تنقید کے کٹہرے میں لا کھڑا کریں۔
چنانچہ ہم نے وہ بیڑا خود اٹھایا جسے اٹھانے والا شاید کوئی موجود نہ تھا۔ ہم نے اپنی بساط بھر تاریخ کے مطالعے کے مادی جدلیاتی اصول وضع کیے، انہیں آزمائش میں ڈالا، اور اسی بنیاد پر اسٹڈی سرکلز کے لیے ایک امدادی نصاب مرتب کیا۔ اسی نصاب کی روشنی میں لیڈ آف تیار کی گئیں، سوال اٹھائے گئے، متون کو کھولا گیا، اور پھر اسٹڈی سرکلز منعقد ہوئے۔ پانچ اسٹڈی سرکلز ہم تسلسل کے ساتھ کر سکے۔ اس کے بعد حالات نے اچانک کروٹ لی، مجھے کراچی جانا پڑا، اور یوں یہ سلسلہ ناگہانی وجوہات کی نذر ہو کر منقطع ہو گیا۔
حوادثِ زمانہ اس کے بعد اس تیزی سے وقوع پذیر ہوئے کہ یہ پورا تجربہ، یہ فکری جستجو، یہ سوال—سب وقتی فراموشی کے دھندلکوں میں گم ہو گئے۔ آج، برسوں بعد، کاغذات کی اسی بے ترتیب جانچ پڑتال میں جب یہ مضمون اور نوٹس اچانک سامنے آ گئے، تو یادوں کا ایک ریلا امڈ آیا۔ یہ محض ماضی کی بازیافت نہیں تھی، بلکہ ایک ادھورے فکری سوال کی واپسی تھی—وہی سوال جو آج بھی پوری شدت کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑا ہے: کیا ہم اپنے مقدس متون، اپنی روحانی روایت اور اپنی قومی تاریخ کو واقعی تاریخ کے مادی جدلیاتی شعور کے ساتھ پڑھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟
آصف خاں کا مضون ” الف اللہ ” کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے
اولیاء اللہ ( اللہ لوکاں ) نے الف کو بہت بڑی اہمیت دی ہے : ع
جس الف مطالعہ کیتا ، ب دا باب نہ پڑھدا ہو
جینہاں شوہ الف تھیں پایا ، پھول قرآن نہ پڑھدے ہو – سلطان باہو
بلھے شاہ
اک الف پڑھو چھٹکارا ہے
اکّو الف تیرے درکار
الف ہکو ہم وس وف میاں جی
ہور کہانی مول نہ بھائی
خواجہ فرید
الف گیئم دل کھس وے میاں جی
شاہ لطیف بھٹائی
اکھّر پڑھ الف جو، ورق سبھ وسار
اندر توں اجار ، پنّا پڑھندیں کیترا
سچل سر مست
ترا در حرف می باید تصور
بود از یک الف صد حرف معنی
اکھروں میں الف ہے ( گیتا باب 10 ، اشلوک 33)
یتریہ آرن یک باب 3 مصرعہ 2،3، 4 میں لکھا ہے :
سارے اکھراں دا تت اکھر الف ہے
سوال پیدا ہوتا ہے کہ سارے اللہ لوکاں اسی (الف) اکھر کو اتنا کیوں “بڑااور عظمت ” والا بنایا اور بھی تو بہت سارے اکھر/ حرف موجود ہیں ۔
پہلی بات تو یہ ہی ہے کہ اکھر الف وہ ہندسے کی طرح لکھا جاتا ہے کہاس کی شکل اس ذات پاک کی طرف توجہ دلاتی ہے جو ایک اور واحد ہے۔ اس سے اس ذات پاک کی احدیت کا نشان ملتا ہے
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
رِگ وید میں کہا گیا ہے ( دو نہیں – وہ ایک برہمن ہے )
سکھوں کے مُول منتر یعنی کلمہ میں اس کی شان احدیت کی پہچان یوں کرائی گئی ہے :
ا (الف) اونکار ، ستنام ، کرتا پرکھ ، نِربھو،نِر ویر، اکال مُورت، اجُونی، سے بھنگ،گُر پرساد
ا (الف) احد، الحق، قادر مطلق، بلا خوف ، بلا دشمنی ، ازلی ، ابدی ، بلا دشمنی،بلا تجسیم، قائم ابلذات،گورو کا وسیلہ
آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس مُول منتر کے اندر اللہ پاک کی احدیت بتانے کے لیے کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ ایک کھڑی لکیر کھینچی گئی ہے ، جو الف اور ایک کے ہندسے جیسی ہے ۔ یہ اسلوب اس لیے اپنایا گیا تاکہ کسی بھی قسم کی بھول اور شبے کا ڈر نہ رہے ۔
الف بارے دوسری بات یہ ہے کہ خداوند کریم کے ھاتی نام یعنی اللہ کا یہ پہلا اکھر ہے جیسے کئی اللہ لوک ( اولیاء اللہ ) “الف اللہ ” کہہ کر بات شروع کرتے ہیں :
الف اللہ یافتم ، ب بہرہ بس
ہر کہ طلبش غیر حق ، اہل از ہوس ( سالطان باہو)
الف اللہ دِل رتّا میرا مینوں رب دی خبر نہ کائی
بلّھے شاہ
اساں پڑھیا علم تحقیقی ہے
ایتھے اکّو حرف حقیقی ہے
ہور جھگڑا سبھ ودھیکی ہے
یہاں یہ ایک حرف الف ہے جو جقیقی ہے ۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے سلطان باہو نے “حک الفقراء خورد” میں کہا ہے ۔ ایک الف ہی ہے جس کے پڑھنے کے ساتھ پڑھنے والا اللہ کے ساتھ ایک مک ہوجاتا ہے ۔۔۔۔ دوئی / ثنویت مک جاتی ہے جو کوئی الف کا محرم ہوجاتا ہے اس پر الف کے علم کے واسطے سے علم کا دروازہ کھل جاتا ہے ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
پڑھ پرھ علم کرن تکبر ملاں کرن وڈیائی ھُو
ساون مانہہ دے بدلاں وانگوں ، پھرن کتاباں چائی ھو
جتھے ویکھن چنگا چوکھا ، پڑھنکلام سوائی ھو
دوہیں جہانیں مُتھے باھُو، جیہناں کھادی ویچ کماٰؒئی ھو
یہاں آکر وہ بات ٹھیک ہوجاتی ہے کہ “العلم حجاب الاکبر ( علم سب سے بڑا پردہ ہے ) یہ پردہ تب ہی ہوتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی معرفت کو پانے کے لیے کھوج نہ کرے – یہ واحدانیت نصیب ہوتی ہے الف کا علم پڑھنے کے راستے سے عشقکی راہ بتانے والا یہی ایک اکھر ہے ۔ جو اس راہ کا مسافر ہوتا ہے بقول باہو اس کا “عامی پن دور ہوگیا اور وہ خدا کی صفات سے آکے جاکر اس کی ذات مین فنا ہوکر ایک ہوجاتا ہے “
( تماہی “انکھ ” کنگن پور – اپریل-مئی ، جون 1991ء )
آصف خان کے مضمون “الف اللہ” کا یہ اقتباس بظاہر ایک روحانی، ثقافتی اور لسانیاتی حسن رکھتا ہے، مگر تاریخ کے مادّی جدلیاتی تصور کی روشنی میں دیکھیں تو یہ حسن خود ایک نظریاتی عمل بن جاتا ہے جس کے اندر کئی اہم تاریخی سوال دب جاتے ہیں۔ اس مضمون کی سب سے بنیادی خصوصیت—اور اسی کے ساتھ سب سے بنیادی مسئلہ—یہ ہے کہ اس میں زمانی ترتیب (historicity) کو معطل کر دیا گیا ہے۔ رِگ وید، آرانیک، گیتا، صوفیانہ کلام اور سکھ مت کے بنیادی متون کو ایک ہی مابعدالطبعی سطح پر رکھ کر “الف” کی ازلی عظمت کے شواہد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یوں مختلف سماجی ادوار، مختلف پیداواری رشتے اور مختلف تاریخی بحران ایک ہی روحانی وحدت میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔
تاریخ کے مادّی جدلیاتی شعور کے لیے یہ پہلا سوال یہی بنتا ہے کہ ہر عہد میں “ایک” یا “الف” کیوں ابھرتا ہے؟ اور یہ ابھار کس سماجی ضرورت کا جواب ہوتا ہے؟
آصف خان کا متن اس سوال کو اٹھانے کے بجائے “الف” کو ایک ماورائی، ازلی اور غیر تاریخی حقیقت بنا دیتا ہے۔ نتیجتاً رِگ وید کے قبائلی سماج میں “ایکَم ست” کا مفہوم، آرانیک کے دور میں “پران = برہمن” کی فکری پیش رفت، گیتا میں اخلاقی و ریاستی بحران کے پس منظر میں “اکشر”، صوفیا کے ہاں ملائیت اور جاگیردارانہ جبر کے خلاف “الف”، اور سکھ مت میں ذات پات و مذہبی اجارہ داری کی نفی کے طور پر “ایک اونکار”—یہ سب اپنے اپنے مادی اور سماجی سیاق سے کٹ کر محض توحید کی ایک مسلسل داستان بن جاتے ہیں۔
یہی وہ مقام ہے جہاں مضمون ایک پنجابی قوم پرستانہ مابعدالطبعیاتی حسیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پنجاب کی تاریخ یہاں طبقاتی جدوجہد، ریاستی تشکیلات، زمین اور پیداوار کے رشتوں کی تاریخ نہیں رہتی، بلکہ ایک مسلسل روحانی وحدت کی تاریخ بن جاتی ہے۔
صوفی ہمیشہ مزاحمت کی علامت، ملا ہمیشہ جبر کی علامت، اور “الف” ہمیشہ نجات کی کنجی بن جاتا ہے۔ مادّی جدلیاتی نقطۂ نظر سے یہ تاریخ کو ہموار (flatten) کرنے کا عمل ہے، جس میں تضادات عشق میں گھل جاتے ہیں اور طاقت کے رشتے نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔
مضمون میں “العلم حجاب الاکبر” جیسے جملے بھی اسی تناظر میں آتے ہیں۔ آصف خان اسے کتابی علم، ملائیت اور تکبر کے خلاف ایک روحانی اعلان کے طور پر پیش کرتے ہیں، مگر تاریخی مادّی شعور یہاں سوال اٹھاتا ہے کہ یہ علم کس کا علم تھا؟ کن اداروں، کن طبقوں اور کن اقتداری رشتوں سے جڑا ہوا تھا؟ صوفیانہ روایت میں یہ جملہ دراصل مدرسے، قاضی اور جاگیردار ریاستی مذہب کے خلاف تھا، نہ کہ علم بطور انسانی پیداوار کے خلاف۔ مضمون میں یہ فرق واضح نہ ہونے کی وجہ سے ایک خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ علم پر تنقید، لاعلمی یا مابعدالطبعی تسلیم و رضا کی تقدیس میں بدل جائے۔
اسی طرح جب رِگ وید یا آرانیک کے حوالہ جات کو براہِ راست “وہ ایک برہمن ہے” یا “سارے اکھراں دا تت اکھر الف ہے” جیسے جملوں میں سمو دیا جاتا ہے، تو یہ ایک anachronistic عمل بن جاتا ہے—یعنی قبائلی اور ماقبل جاگیرداری سماج کے فکری اشاروں کو بعد کی مکمل مابعدالطبعی توحید میں جذب کر لینا۔ اس عمل میں قدیم متون کی اپنی جدوجہد، اپنی فکری بے چینی اور اپنے سماجی تضادات گم ہو جاتے ہیں، اور وہ بعد کی مذہبی و قوم پرستانہ تعبیر کا خام مال بن کر رہ جاتے ہیں۔
تاریخ کے مادّی جدلیاتی شعور کی روشنی میں دیکھا جائے تو آصف خان کا مضمون ایک طرف پنجابی صوفیانہ روایت کی داخلی وحدت کو نہایت دلکش انداز میں جوڑتا ہے اور ایک طاقتور ثقافتی بیانیہ تخلیق کرتا ہے، مگر دوسری طرف وہ تاریخ کو غیر زمانی بنا کر سماجی و طبقاتی تضادات کو مابعدالطبعیات میں حل کر دیتا ہے۔ “الف” یہاں سوال نہیں رہتا بلکہ جواب بن جاتا ہے—ایسا جواب جو سماج کی بکھری ہوئی حقیقت کو سمجھنے کے بجائے اسے روحانی تسلی میں بدل دیتا ہے۔
اس لیے مادّی جدلیاتی متبادل پڑھت یہ کہتی ہے کہ رِگ وید سے صوفیا تک “الف” کوئی ازلی سچ نہیں، بلکہ ہر دور میں بکھرتے ہوئے سماجی رشتوں کو جوڑنے کی ایک فکری کوشش ہے۔ جب یہ کوشش حاشیے سے اٹھ کر جبر کے خلاف اخلاقی سوال بنتی ہے تو اس میں مزاحمت کی قوت ہوتی ہے، اور جب اسے تاریخ، پیداوار اور طاقت کے رشتوں سے کاٹ دیا جائے تو یہی “الف” وحدت کے بجائے پردہ بن جاتا ہے۔ تاریخ کے مادّی جدلیاتی شعور کے لیے ضروری ہے کہ ہم “الف” سے متاثر بھی ہوں، مگر اس سے سوال اٹھانے کی جرات بھی رکھیں—کیونکہ جو وحدت سوال سے خالی ہو جائے، وہ نجات نہیں بلکہ نظریاتی سکون بن جاتی ہے۔
آصف خان کے ہاں “الف” ایک ایسی مابعدالطبعی وحدت میں ڈھل جاتا ہے جو رِگ وید کے “ایک”، گیتا کے “اکشر”، آرانیک کے “تت”، صوفی کے “الف” اور سکھ مت کے “ایک اونکار” کو ایک ہی لڑی میں پرو دیتی ہے۔ اس بیانیے میں یہ تمام متون اور روایات اپنے تاریخی تفاوت، زمانی فاصلوں اور سماجی تضادات سے آزاد ہو کر خدا کی ازلی اور ابدی احدیت کے شواہد بن جاتے ہیں۔ یوں “الف” ایک ایسی ماورائی حقیقت کی علامت بن کر سامنے آتا ہے جو ہر دور میں یکساں، مکمل اور غیر متغیر سمجھی جاتی ہے۔
مگر تاریخ کا مادّی جدلیاتی شعور اسی مقام پر سوال اٹھاتا ہے۔ وہ یہ پوچھتا ہے کہ یہ “ایک” ہر دور میں آخر کیوں ابھرتا ہے، اور کن سماجی، معاشی اور فکری ضرورتوں کے تحت اسے مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے؟ آصف خان کا متن اس سوال کو معطل کر دیتا ہے۔ وہ “ایک” کو تاریخ کے اندر پیدا ہونے والا تصور نہیں، بلکہ تاریخ پر حاوی ایک ماورائی سچ بنا دیتا ہے۔ نتیجتاً یہ دریافت نہیں ہو پاتی کہ قبائلی سماج میں “ایک” کی بات مشترک پیداوار اور اجتماعی بقا کے احساس سے کیوں جڑی تھی، یا جاگیرداری بحران کے عہد میں گیتا کا “اکشر” اخلاقی و سماجی شکست کو سہنے کے لیے کیوں مرکزِ فکر بنا۔
اسی طرح یہ سوال بھی پس منظر میں چلا جاتا ہے کہ صوفیا کے ہاں “الف” کیوں ملائیت، رسمی شریعت اور ریاستی مذہب کے خلاف ایک احتجاجی علامت کے طور پر ابھرا، اور سکھ مت میں “ایک اونکار” کیوں ذات پات، برہمنیت اور مذہبی اجارہ داری کی نفی کی صورت اختیار کر گیا۔ مادّی جدلیاتی نظر میں یہ سب الگ الگ تاریخی لمحے ہیں، جن میں “وحدت” کا تصور مختلف سماجی تضادات کا جواب تھا، نہ کہ ایک ہی ازلی حقیقت کا مسلسل ظہور۔
یوں آصف خان کے متن میں “الف” کی تاریخی مادّی شرطیں غائب ہو جاتی ہیں۔ “ایک” سوال بننے کے بجائے جواب بن جاتا ہے، اور سماج کی پیچیدہ، متضاد اور طبقاتی حقیقت ایک روحانی وحدت میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ مادّی جدلیاتی شعور کے لیے اصل مسئلہ یہی ہے: جب وحدت کو تاریخ سے کاٹ دیا جائے تو وہ انسانی جدوجہد کی توضیح نہیں رہتی، بلکہ اس جدوجہد پر ایک حسین مگر خاموش پردہ ڈال دیتی ہے۔
یہ مضمون دراصل پنجابی قوم پرستانہ مابعدالطبعیاتی حسیت کی ایک نمائندہ صورت ہے، جس میں پنجاب کی تاریخ کو سماجی، معاشی اور سیاسی تشکیل کے بجائے ایک مسلسل روحانی وحدت کی تاریخ میں بدل دیا جاتا ہے۔ اس بیانیے میں تاریخی تضادات—طبقاتی کشمکش، زمین کی ملکیت، ریاستی جبر، علاقائی اور لسانی تفاوت—سب عشق، وحدت اور باطنی تجربے کی زبان میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ یوں تاریخ ایک مادی جدوجہد کے بجائے ایک روحانی سفر بن کر سامنے آتی ہے، جہاں اصل سوالات پس منظر میں دھکیل دیے جاتے ہیں۔
تاریخ کے مادّی جدلیاتی تصور میں اس عمل کو Ideological flattening of history کہا جاتا ہے، یعنی تاریخ کو نظریاتی طور پر ہموار کر دینا۔ اس ہمواری میں صوفی کو ازل سے مزاحمت کی علامت بنا دیا جاتا ہے، ملا کو ازل سے جبر کا استعارہ، اور پنجاب کو ایک ایسی ازلی وحدت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس میں نہ دراڑ ہے، نہ کشمکش، نہ اختلاف۔ اس طرح ایک پیچیدہ اور متضاد سماجی تاریخ ایک اخلاقی اور روحانی تمثیل میں سمٹ جاتی ہے۔
مگر تاریخی حقیقت اس تصور سے کہیں زیادہ متنوع اور متصادم رہی ہے۔ صوفیا محض حاشیے کی مزاحم آواز نہیں رہے؛ کئی مواقع پر وہ خود جاگیردارانہ نظم، خانقاہی معیشت اور ریاستی سرپرستی کا حصہ بنے۔ اسی طرح پنجاب کوئی یک رنگ، یک آواز خطہ نہیں رہا بلکہ یہاں طبقاتی استحصال، لسانی و علاقائی تقسیم، مرکز اور حاشیے کی کشمکش، اور ریاستی طاقت کے مختلف روپ ہمیشہ موجود رہے۔ “وحدت” کا تصور اکثر ان تضادات کو حل کرنے کے بجائے دبانے اور غیر مرئی بنانے کا ذریعہ بنا، تاکہ سماجی ناہمواری کو روحانی ہم آہنگی کے پردے میں چھپایا جا سکے۔
یوں پنجابی قوم پرستانہ مابعدالطبعیات تاریخ کو سمجھنے کے بجائے اسے ایک اخلاقی اور ثقافتی داستان میں بدل دیتی ہے۔ مادّی جدلیاتی شعور کے لیے مسئلہ یہ نہیں کہ وحدت کی بات کیوں کی گئی، بلکہ یہ ہے کہ اس وحدت کے نام پر کن تضادات کو خاموش کر دیا گیا۔ کیونکہ جب وحدت سماجی کشمکش کی نفی بن جائے، تو وہ نجات کا راستہ نہیں رہتی بلکہ تاریخ پر پڑا ہوا ایک حسین مگر بھاری پردہ بن جاتی ہے۔
آصف خان کے مضمون میں جس مقام پر یہ جملہ سامنے آتا ہے کہ “العلم حجاب الاکبر”، وہاں اسے وہ بنیادی طور پر ملا کے تکبر، کتابی علم اور رسمی مذہب کے خلاف ایک روحانی اور اخلاقی نعرے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کے بیانیے میں یہ جملہ علم کی اُس صورت پر کاری ضرب بن جاتا ہے جو روحانی تجربے، عشق اور باطنی سچائی کے مقابل ایک خشک، مغرور اور جابرانہ قوت کے طور پر دکھائی دیتی ہے۔ اس سطح پر یہ موقف دلکش بھی ہے اور صوفیانہ روایت کی ایک معروف لسانی فضا سے ہم آہنگ بھی، مگر تاریخ کے مادّی جدلیاتی شعور کے لیے یہیں سے سوالات جنم لیتے ہیں۔
مادّی جدلیاتی مطالعہ اس مقام پر ایک اضافی مگر ناگزیر سوال اٹھاتا ہے: یہ جملہ آخر کن علموں کے خلاف تھا؟ کس طبقے کے علم کے خلاف؟ اور کن اداروں کے علم کے خلاف؟ کیونکہ علم کوئی مجرد، ماورائی شے نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کسی نہ کسی سماجی ڈھانچے، ادارے اور طبقاتی مفاد سے جڑا ہوتا ہے۔ صوفیانہ روایت میں “العلم حجاب الاکبر” کا نعرہ دراصل علمِ مطلق یا انسانی عقل کے انکار کے لیے نہیں تھا، بلکہ اُس مخصوص علم کے خلاف تھا جو مدرسے، قاضی، فقہ اور جاگیردارانہ ریاستی مذہب کے ذریعے طاقت اور نظم کے استحکام کا ذریعہ بن چکا تھا۔ یہ نعرہ اُس علم کے خلاف تھا جو سوال پیدا کرنے کے بجائے اطاعت سکھاتا تھا، جو سماجی ناہمواری کو تقدیس بخشتا تھا، اور جو اقتدار کی زبان میں بولتا تھا۔
اسی لیے صوفیا کے ہاں یہ جملہ ایک طبقاتی مفہوم رکھتا تھا۔ یہ نیچے سے اوپر اٹھنے والی اخلاقی بغاوت کی زبان تھی، جو ریاستی مذہب اور جاگیردارانہ اشرافیہ کے علمی جواز کو چیلنج کرتی تھی۔ مگر آصف خان کے متن میں یہ تاریخی تخصیص دھندلا جاتی ہے۔ جب علم پر تنقید کو ایک عمومی اور ماورائی سطح پر منتقل کر دیا جاتا ہے تو یہ فرق مٹ جاتا ہے کہ تنقید علم کی کس شکل پر ہو رہی ہے۔ نتیجتاً ایک خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ علم پر کی گئی یہ تنقید، لاعلمی، وجدانی سرنڈر یا محض روحانی تسلیم و رضا کی تقدیس میں بدل جائے۔
تاریخ کے مادّی جدلیاتی شعور کے مطابق اصل مسئلہ علم اور عشق، عقل اور روحانیت کی دوئی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ علم کس کے ہاتھ میں ہے، کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور کس سماجی رشتے کو برقرار رکھتا ہے۔ جب یہ سوال غائب ہو جاتا ہے تو “العلم حجاب الاکبر” جیسا جملہ اپنی تنقیدی اور انقلابی معنویت کھو بیٹھتا ہے اور ایک مبہم روحانی فقرے میں ڈھل جاتا ہے۔ یوں وہ نعرہ جو کبھی جبر کے علمی ڈھانچوں کو بے نقاب کرنے کا آلہ تھا، خود ایک ایسا پردہ بننے لگتا ہے جو سماج، طبقے اور اقتدار کے حقیقی سوالات کو اوجھل کر دیتا ہے۔
آصف خان جب یہ لکھتے ہیں کہ “رِگ وید میں کہا گیا ہے: دو نہیں، وہ ایک برہمن ہے” تو دراصل وہ ایک اہم نظریاتی جست لگاتے ہیں۔ اس جست میں رِگ وید کے مشہور منتر “ایکَم ست، وِپرا بہُدھا وَدَنتی” اور آرانیک متون کے اس تصور کو، جس میں پران کو برہمن کہا گیا ہے، براہِ راست ایک مکمل اور منظم توحیدی مابعدالطبعیات میں بدل دیا جاتا ہے۔ یوں مختلف تاریخی ادوار میں پیدا ہونے والے فکری اشارے ایک ہی مذہبی مفہوم کے شواہد بن جاتے ہیں، جیسے یہ سب ابتدا ہی سے ایک ہی ازلی سچ کی زبان بول رہے ہوں۔
تاریخ کے مادّی جدلیاتی شعور کے مطابق یہ عمل ایک واضح anachronism ہے، یعنی تاریخی سیاق و سباق کو توڑ کر مختلف زمانوں کے تصورات کو بعد کے فکری ڈھانچے میں فِٹ کر دینا۔ رِگ وید کا “ایکَم ست” قبائلی سماج کے اندر کثرتِ دیوتا اور فطری قوتوں کے باوجود ایک عملی اور تجربی وحدت کی طرف اشارہ تھا—یہ وحدت مشترک چراگاہی معیشت، اجتماعی بقا اور قبائلی رشتوں کی پیداوار تھی، نہ کہ کسی مجرد، فلسفیانہ توحید کا اعلان۔ اسی طرح آرانیک متون میں “پران = برہمن” کہنا قربانیاتی رسم سے ہٹ کر زندگی، سانس اور شعور کے ایک مرکزی اصول کی تلاش تھی، جو سماج کی بدلتی ہوئی مادی بنیادوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔
جب ان دونوں کو براہِ راست “وہ ایک برہمن ہے” جیسے جملے میں سمو دیا جاتا ہے تو قبائلی اور ماقبل جاگیرداری سماج کی فکری جدوجہد، ان کی بے یقینی، ان کے سوال اور ان کے تضادات غائب ہو جاتے ہیں۔ وحدت کی یہ ابتدائی، غیر مستحکم اور تجربی شکلیں بعد کی منظم مذہبی فلسفہ سازی کا خام مال بن جاتی ہیں۔ یوں ایسا تاثر پیدا ہوتا ہے جیسے قدیم سماج پہلے ہی وہی کچھ جانتا تھا جسے بعد کے صدیوں میں ویدانت، صوفیانہ یا توحیدی فلسفے نے باقاعدہ نظام کی شکل دی۔
مادّی جدلیاتی نقطۂ نظر سے مسئلہ یہ نہیں کہ وحدت کا تصور قدیم متون میں موجود تھا، بلکہ یہ ہے کہ وہ وحدت کس سماجی مرحلے پر، کن مادی حالات میں اور کن ضرورتوں کے تحت سامنے آئی۔ جب ان سوالات کو معطل کر دیا جائے تو تاریخ ایک ارتقائی، جدلیاتی عمل کے بجائے ایک مسلسل مابعدالطبعی سچ کی کہانی بن جاتی ہے۔ اس عمل میں قدیم سماج اپنی خود مختار فکری حیثیت کھو دیتا ہے اور محض اس بات کا ثبوت رہ جاتا ہے کہ بعد کی مذہبی توحید “ہمیشہ سے موجود” تھی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں رِگ وید اور آرانیک کا استعمال وضاحت کے بجائے نظریاتی جست بن جاتا ہے، اور تاریخ تحقیق کے بجائے تعبیر کا شکار ہو جاتی ہے۔
تاریخ کے مادّی جدلیاتی شعور کی روشنی میں آصف خان کے مضمون “الف اللہ” سے جو حتمی نتیجہ نکلتا ہے، وہ دوہرا اور جدلیاتی ہے، نہ یک رُخی اور نہ محض نفی پر مبنی۔ ایک طرف یہ مضمون ایک طاقتور ثقافتی اور روحانی بیانیہ ہے جو پنجابی صوفی روایت کے مختلف متون، لہجوں اور استعاروں کو ایک دلکش داخلی وحدت میں پرو دیتا ہے۔ اس میں زبان کی جمالیات، روایت کی تسلسل پسندی اور روحانی تجربے کی شدت ایسی قوت رکھتی ہے کہ قاری کو پنجاب کی صوفیانہ تاریخ ایک زندہ، مربوط اور معنی خیز کُل کی صورت میں دکھائی دیتی ہے۔ اس سطح پر یہ تحریر پنجابی ثقافتی شعور کی ایک معتبر اور پراثر نمائندگی بنتی ہے۔
مگر اسی کے ساتھ مادّی جدلیاتی نقطۂ نظر یہ بھی واضح کرتا ہے کہ یہ بیانیہ اپنی جمالیاتی اور روحانی قوت کے عوض تاریخ کی زمانیت قربان کر دیتا ہے۔ مختلف سماجی ادوار—قبائلی، ماقبل جاگیرداری، جاگیرداری، اور نوآبادیاتی—ایک ہی مابعدالطبعی افق میں جذب ہو جاتے ہیں۔ نتیجتاً سماجی و طبقاتی تضادات، زمین اور پیداوار کے رشتے، ریاستی تشکیل اور اقتدار کی حرکیات عشق، وحدت اور روحانیت کی زبان میں حل کر دی جاتی ہیں۔ “الف” یہاں ایک ایسا جواب بن جاتا ہے جو سوال پیدا کرنے کے بجائے سوال کو خاموش کر دیتا ہے، اور تاریخ کو جدلیاتی کشمکش کے بجائے ایک روحانی تسلسل میں بدل دیتا ہے۔
مادّی جدلیاتی متبادل پڑھت اسی مقام پر مداخلت کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ رِگ وید سے لے کر صوفیا تک “الف” کسی ازلی اور ماورائی سچ کا نام نہیں، بلکہ ہر تاریخی دور میں بکھرتے ہوئے سماجی رشتوں کو جوڑنے کی ایک فکری کوشش ہے۔ کبھی یہ قبائلی وحدت کی علامت بنتا ہے، کبھی جاگیرداری بحران میں اخلاقی سہارا، کبھی ملائیت اور ریاستی مذہب کے خلاف احتجاج، اور کبھی ذات پات و سماجی درجہ بندی کی نفی۔ لیکن جب اس “الف” کو اس کی تاریخی مادّی شرطوں سے کاٹ دیا جاتا ہے تو وہ مزاحمت، سوال اور بغاوت کی علامت نہیں رہتا بلکہ ایک ثقافتی تسلی میں ڈھل جاتا ہے—ایسی تسلی جو سماج کو سمجھنے کے بجائے اسے روحانی طور پر قابلِ برداشت بنا دیتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مادّی جدلیاتی شعور “الف” سے انکار نہیں کرتا، بلکہ اسے دوبارہ تاریخ کے اندر لا کر سوال بناتا ہے، تاکہ وحدت نجات کا راستہ بنے، پردہ نہیں۔
آصف خان کا مضمون بلاشبہ پنجابی روحانی شعور کی ایک نہایت خوبصورت، بلیغ اور متاثر کن دستاویز ہے، جو صوفیانہ روایت کی جمالیات، وحدت کے استعاروں اور ثقافتی حافظے کو دل آویز انداز میں یکجا کرتی ہے۔ یہ تحریر قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے اور “الف” کو ایک ایسی روحانی علامت کے طور پر پیش کرتی ہے جو معنی، محبت اور شناخت کے کئی دریچے کھولتی ہے۔ مگر تاریخ کے مادّی جدلیاتی شعور کے لیے یہی مقام محض تحسین کا نہیں بلکہ سوال کا بھی بنتا ہے۔ اس شعور کا تقاضا ہے کہ ہم “الف” سے متاثر ضرور ہوں، مگر اس کے سامنے سرِ تسلیم خم کرنے کے بجائے اسے تاریخ، سماج اور طاقت کے رشتوں کے کٹہرے میں بھی کھڑا کریں۔ کیونکہ جیسے ہی “الف” سوال بننا چھوڑ دیتا ہے، جیسے ہی وہ اپنی تاریخی مادّی شرطوں سے کٹ کر ایک ازلی اور ماورائی جواب میں بدل جاتا ہے، وہ وحدت کی علامت نہیں رہتا بلکہ ایک ایسا پردہ بن جاتا ہے جو سماجی تضادات، طبقاتی کشمکش اور تاریخی جدلیات کو نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے۔ مادّی جدلیاتی شعور کے لیے نجات اسی میں ہے کہ “الف” کو وحدت کے حسن کے ساتھ ساتھ سوال کی کاٹ بھی دی جائے—تاکہ وہ تسلی نہیں، شعور بنے؛ پردہ نہیں، دریچہ بنے۔
اس مضمون کی تاریخ کے مادّی جدلیاتی تصور کی روشنی میں جانچ کرتے ہوئے یہ بات نہایت اہم ہے کہ اسے اس کے زمانی، سیاسی اور فکری سیاق سے الگ کر کے نہیں پڑھا جا سکتا۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ آصف خان کا مضمون 1990ء کی دہائی کے آغاز میں لکھا گیا، یعنی اُس تاریخی لمحے میں جب پاکستان—خصوصاً پنجاب—ابھی جنرل ضیاء الحق کی مذہبی آمریت کے گہرے اثرات سے پوری طرح باہر نہیں نکلا تھا۔ یہ وہ دور تھا جس میں فرقہ واریت، جہاد ازم، نفاذِ شریعت کے گرد گھومنے والی سیاست، اور سیاسی اسلام کے منظم بیانیے نے پنجاب کی صدیوں پرانی مذہبی رواداری، ثقافتی ہم آہنگی اور صوفیانہ روایت کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ ایسے میں “الف اللہ” جیسے مضامین محض ادبی یا روحانی تحریریں نہیں تھے بلکہ ایک ثقافتی مزاحمتی عمل بھی تھے۔
آصف خان کا مضمون دراصل پنجابی زبان و ادب میں موجود اس ترقی پسند ادبی سیکشن کے بیانیے کا تسلسل ہے جو 1970ء اور 1980ء کی دہائی میں رجعت پسندانہ ادبی ڈسکورس کے جواب میں تشکیل پایا تھا۔ یہ رجعت پسند ڈسکورس ایک طرف سیاسی اسلام پسند دائیں بازو کے ادیبوں—خصوصاً جماعت اسلامی سے متاثرہ نسیم حجازی جیسے مصنفین—کے ذریعے ترتیب دیا جا رہا تھا، اور دوسری طرف حسن عسکری، سلیم احمد اور انتظار حسین جیسے ادیبوں کے ہاں، جو براہِ راست جماعت اسلامی سے وابستہ نہ ہونے کے باوجود دو قومی نظریے، اردو مرکزیت اور ایک خاص مابعدالطبعیاتی اسلامی تہذیبی تصور کو فروغ دے رہے تھے۔ پنجابی ترقی پسند ادبی دھارے نے اس کے ردعمل میں مقامی تاریخ، ویدک متون، قدیم مقدس صحائف اور صوفیانہ روایت میں موجود اینٹی ملاں، اینٹی قاضی اور اینٹی پروہت تصورات کو اجاگر کیا اور انہیں پنجابی ثقافت کی ایک مسلسل، داخلی روایت کے طور پر پیش کیا۔
تاہم مادّی جدلیاتی نقطۂ نظر سے مسئلہ یہیں پیدا ہوتا ہے کہ اس عمل میں ان تصورات کو ان کے اپنے تاریخی ادوار کے مادی حالات، سماجی تضادات اور پیداواری رشتوں سے بڑی حد تک کاٹ دیا گیا۔ رِگ وید، آرانیک، صوفیانہ متون اور سکھ گروؤں کے کلام کو ایک ایسی ثقافتی لڑی میں پرو دیا گیا جس میں یہ سب ایک لچک دار، انسان دوست اور روادار مابعدالطبعیاتی مذہب کے شواہد بن گئے، جو ایک سخت گیر، قانونی اور ریاستی مذہب کے مقابل کھڑا تھا۔ یہ دراصل مذہب کی تشکیلِ جدید کی ایک کوشش تھی—یعنی ایک مابعدالطبعیات کو دوسری مابعدالطبعیات کے مقابل لا کھڑا کرنا۔
اس کوشش کی تاریخی معنویت اپنی جگہ مسلم ہے۔ ضیائی آمریت کے مقابل یہ پنجابی قوم پرستانہ ادبی حسیت واقعی ایک ثقافتی بند باندھنے کی سعی تھی، تاکہ پنجاب میں فرقہ واریت، مذہبی جبر اور عسکری اسلام کے سیلاب کے آگے رواداری اور صوفیانہ روایت کو بچایا جا سکے۔ مگر تاریخ کے مادّی جدلیاتی شعور کے لیے یہی وہ مقام ہے جہاں یہ حسیت اپنی حدوں کو چھو لیتی ہے۔ کیونکہ اس سارے عمل میں پنجابی سماج کے اندر پیداواری رشتوں کی تبدیلی، سرمایہ دارانہ طریقِ پیداوار کے مخصوص ارتقا، اور سرمایہ داری کی ناہموار ترقی سے تشکیل پانے والی جدید طبقاتی ساخت تقریباً مکمل طور پر نظرانداز ہو جاتی ہے۔ ثقافت اور روحانیت مزاحمت کا میدان بن جاتی ہے، مگر معیشت اور طبقہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔
اسی تناظر میں ایک اور بنیادی سوال ابھرتا ہے جس پر اس طرز کی پنجابی قوم پرستانہ ترقی پسند فکر نے سنجیدگی سے غور نہیں کیا۔ 1970ء کی دہائی کے آخر میں ملتان سے لے کر سابق ریاست بہاولپور، ڈی جی خان ڈویژن، سرگودھا ڈویژن کے بعض اضلاع (میانوالی، بھکر) اور ڈیرہ اسماعیل خان تک جو ترقی پسند ادبی و لسانی تحریک ابھری، وہ کیوں الگ زبان (سرائیکی) اور پھر سیاسی اعتبار سے سرائیکی قومی سوال کی صورت میں سامنے آئی؟ یہ تحریک کیوں محض پنجابی ثقافتی وحدت کے اندر ضم نہ ہو سکی، بلکہ ایک الگ مرکز، الگ شناخت اور الگ سیاسی مطالبے کے ساتھ ابھری؟
مادّی جدلیاتی نقطۂ نظر سے یہ محض لسانی یا ثقافتی اختلاف کا سوال نہیں تھا بلکہ سرمایہ دارانہ ترقی کی ناہمواری، مرکز اور حاشیے کی تشکیل، اور وسائل و اقتدار کی غیر مساوی تقسیم کا نتیجہ تھا۔ مگر پنجابی قوم پرستانہ ترقی پسند ادبی حسیت—جس کی نمائندگی آصف خان جیسے مضامین کرتے ہیں—اکثر اس سوال کی طرف بڑھنے کے بجائے اس کی نفی یا نظراندازی کی طرف مائل رہی۔ پنجابی وحدت کو ایک روحانی اور ثقافتی تسلسل کے طور پر پیش کرتے ہوئے اس نے اس حقیقت کا سامنا نہیں کیا کہ جدید پنجاب خود اندر سے طبقاتی، علاقائی اور لسانی طور پر منقسم ہو چکا تھا۔
یوں تاریخ کے مادّی جدلیاتی شعور کی روشنی میں آصف خان کا مضمون ایک طرف اپنے عہد کی ایک جائز، ضروری اور باوقار ثقافتی مزاحمت کی دستاویز ہے، مگر دوسری طرف یہ اس مزاحمت کی حدود کو بھی آشکار کرتا ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جب مذہبی جبر کے مقابل ثقافت کو واحد میدانِ مزاحمت بنا لیا جائے اور پیداواری رشتوں، طبقاتی ساخت اور حاشیوں کی ابھرتی ہوئی سیاست کو نظرانداز کر دیا جائے، تو ترقی پسندی بھی ایک مابعدالطبعیاتی قوم پرستی میں بدل سکتی ہے—جو سوال اٹھانے کے بجائے وحدت کے نام پر نئے سوالوں کو دبانے لگتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اس بیانیے کو تاریخی ہمدردی کے ساتھ، مگر بے لاگ مادّی جدلیاتی تنقید کے ساتھ پڑھنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔
اس پوری بحث کی روشنی میں آج پنجابی ترقی پسندی کا تقاضا ماضی کی جمالیاتی بازیافت یا محض ثقافتی مزاحمت نہیں رہ جاتا، بلکہ ایک نئے تاریخی، سماجی اور طبقاتی شعور کی تشکیل بن جاتا ہے۔ اگر 1980ء اور 1990ء کی دہائی میں پنجابی ترقی پسندی کا بنیادی فریضہ ضیائی آمریت، مذہبی فسطائیت اور سیاسی اسلام کے مقابل ایک روادار، صوفیانہ اور انسان دوست ثقافتی بیانیہ کھڑا کرنا تھا، تو آج حالات بدل چکے ہیں۔ آج وہی بیانیہ—اگر خود کو ازسرِنو نہ بدلے—مزاحمت کے بجائے تسلی اور نوستالجیا میں بدل جانے کا خطرہ رکھتا ہے۔
آج پنجابی ترقی پسندی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ مابعدالطبعیاتی وحدت سے آگے بڑھے۔ “الف”، “عشق”، “وحدت” اور “صوفیانہ روایت” کو ازلی اور ماورائی سچ ماننے کے بجائے انہیں ان کے تاریخی، مادی اور طبقاتی سیاق میں رکھ کر سمجھے۔ سوال یہ نہیں کہ یہ تصورات خوبصورت ہیں یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ کس سماجی لمحے میں کیوں ابھرے اور آج کن مفادات کی خدمت کر رہے ہیں۔ جو وحدت سوال سے خالی ہو جائے، وہ آج کے پنجاب میں جبر کو چیلنج نہیں کرتی بلکہ اکثر اس پر تہذیبی پردہ ڈال دیتی ہے۔
دوسرا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ پنجابی ترقی پسندی پیداواری رشتوں اور طبقاتی ساخت کو اپنی فکر کے مرکز میں واپس لائے۔ آج کا پنجاب زرعی جاگیرداری، کمرشل ایگری کلچر، شہری سرمایہ داری، غیر رسمی مزدوری، اوورسیز لیبر، اور ریاستی–کارپوریٹ گٹھ جوڑ کا پیچیدہ امتزاج ہے۔ اس سماج میں مزدور، ہاری، چھوٹا کسان، شہری محنت کش، عورت، اور بے زمین طبقہ کن حالات میں جی رہا ہے—یہ سوال اگر پنجابی ادب، تنقید اور سیاست کے متن میں شامل نہیں، تو وہ ترقی پسند نہیں بلکہ محض ثقافتی ہے۔
تیسرا اور نہایت اہم تقاضا یہ ہے کہ پنجابی ترقی پسندی سرائیکی قومی سوال اور دیگر علاقائی/لسانی تضادات کا سامنا کرے، نہ کہ ان کی نفی کرے۔ یہ ماننا ہوگا کہ سرائیکی تحریک محض “غلط فہمی” یا “تقسیم” نہیں بلکہ پنجاب میں سرمایہ داری کی ناہموار ترقی، مرکز–حاشیہ کے تضاد اور وسائل کی غیر مساوی تقسیم کا نتیجہ ہے۔ آج کی پنجابی ترقی پسندی اگر واقعی ترقی پسند ہے تو اسے پنجابی وحدت کو ایک روحانی تسلسل کے بجائے برابر، رضاکارانہ اور کثیر قومی رشتے کے طور پر تصور کرنا ہوگا—ایسا رشتہ جس میں سرائیکی، پوٹھوہاری، جھنگوچی اور دیگر شناختیں دبائی نہ جائیں بلکہ سیاسی طور پر تسلیم کی جائیں۔
چوتھا تقاضا یہ ہے کہ پنجابی ترقی پسندی ثقافت کو واحد میدانِ مزاحمت ماننے سے آگے بڑھے۔ ادب، زبان اور روایت اہم ہیں، مگر وہ کافی نہیں۔ آج مزاحمت کے میدان معیشت، ریاست، قانون، زمین، پانی، محنت اور وسائل کی سیاست میں ہیں۔ اگر پنجابی ترقی پسندی ان میدانوں سے کٹ کر صرف شاعری، صوفیانہ حوالوں اور ثقافتی میلوں تک محدود رہے گی تو وہ نظام کے لیے بے ضرر ہو جائے گی—خواہ اس کی زبان کتنی ہی باغی کیوں نہ ہو۔
آخر میں، آج پنجابی ترقی پسندی کا سب سے گہرا تقاضا یہ ہے کہ وہ سوال کو زندہ رکھے۔ “الف” کو جواب نہیں بلکہ سوال بنائے؛ وحدت کو منزل نہیں بلکہ جدوجہد کا میدان سمجھے؛ اور تاریخ کو روحانی تسلسل نہیں بلکہ جدلیاتی تصادم کے طور پر پڑھے۔ ایسی پنجابی ترقی پسندی نہ ماضی سے انکار کرے گی، نہ اس کی اسیر ہوگی، بلکہ ماضی کو اس طرح کھولے گی کہ حال کے طبقاتی جبر، علاقائی ناانصافی اور سرمایہ دارانہ استحصال کے خلاف ایک نئی، ٹھوس اور باخبر سیاست جنم لے سکے۔ یہی آج کی پنجابی ترقی پسندی کا حقیقی امتحان ہے۔